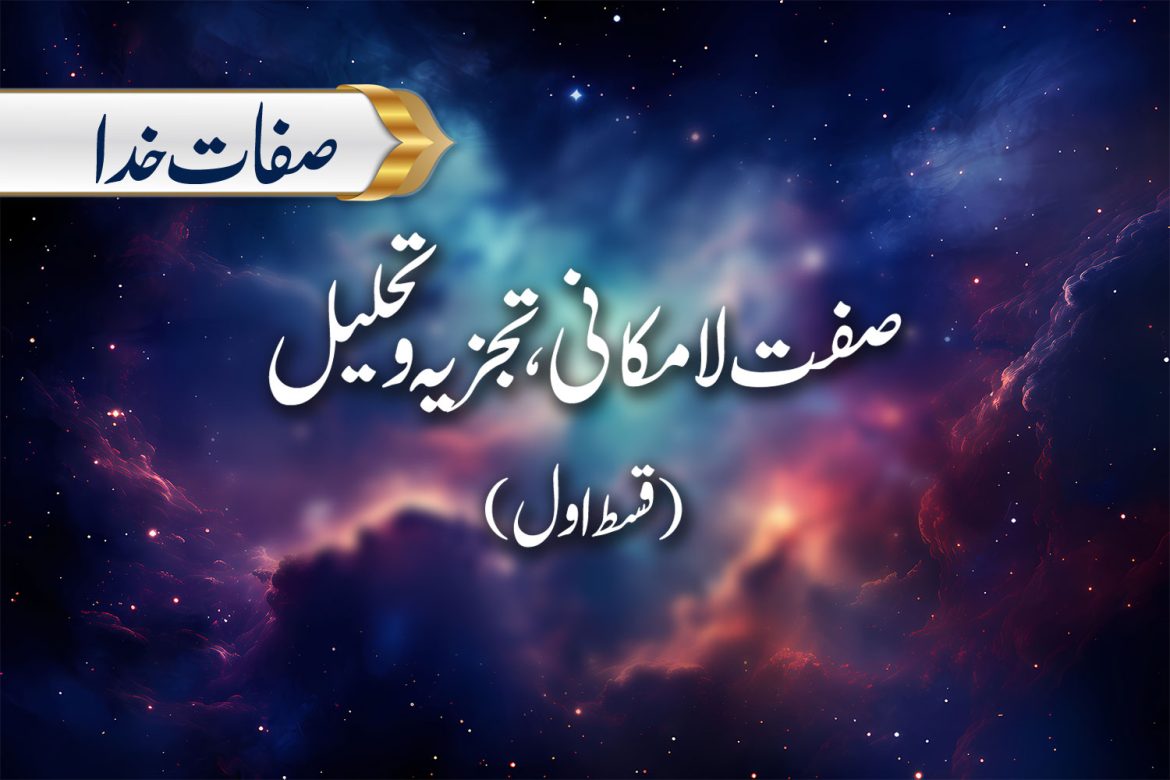Table of Contents
غلام رسول وَلایتی ریسرچ ایسوسی ایٹ ڈپارٹمنٹ آف فیتھ اینڈ ریزن
مقدمہ
یہ ایک نہایت اہم اور گہرا موضوع ہے، کیونکہ اللہ کی صفتِ لامکانی کا سمجھنا ہماری معرفتِ الٰہی میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ امیرالمؤمنینؑ اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے ارشادات میں بارہا اس حقیقت پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ اللہ مکان اور زمان سے ماورا ہے۔
لامکانی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کسی خاص جگہ میں محدود نہیں ہے، کیونکہ مکانیت خود مخلوقات کی صفات میں سے ہے۔ اگر کوئی چیز مکانی ہو، تو وہ لازمی طور پر کسی حد، جہت اور قیود کی محتاج ہوگی، جبکہ اللہ ان سب قیود سے پاک ہے۔ اس مضمون میں آپ اس بات کو مزید وضاحت کے ساتھ جان سکیں گے کہ کیوں اللہ کو کسی مکان میں تصور کرنا درست نہیں، اور اسلامی فلسفہ و کلامِ جدید میں اس حقیقت کی بہترین تشریح کی گئی ہے۔
صفات
عربی لغت میں صفت، "وَعَدَ یَعِدُ” کے باب سے ہے، جب کوئی شخص ایسے کپڑے پہنے کہ جس سے جسمانی کیفیت اور ہیئت ظاہر ہوجائے تو وَصَفَ الثوبُ الجسمَ کہتے ہیں، اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ کسی شے کی خصوصیت، کیفیت یا ہیئت کو واضح اور ظاہر کرنے کو صفت کہتے ہیں۔ جبکہ علمِ الہیات کی اصطلاح میں ذاتِ واجب کی صفات کا ذکر کرنا اور اس کی پاکیزگی بیان کرنا صفت(attribute)کہلاتا ہے۔
کنہ ذات و صفات
کُنہِ ذات (very nature)اور صفات(Devine attributes) یعنی اس ذاتِ احدیت اور اس کی صفات کی حقیقت کو کنہ ذات و صفات کہا جاتاہے، ذات واجب کی کنہ صفات و ذات تک کسی کی رسائی نہیں ہے کیونکہ عقل(intellect)، وہم(fantasy)،خیال (imagination)،تفکر (cogitation)اور حواس(sensation) ایسی چیزوں کو درک کرسکتے ہیں جس کی کوئی ماہیت(quiddity)، کمیت (quantity)یا کیفیت(quality) ہو لیکن جس کی کوئی ماہیت، کمیت یا کیفیت نہ ہوعقل، وہم،خیال،تفکر اور حواس اسے تصور بھی نہیں کرسکتے ہیں۔ عقل فقط انھیں چیزوں کا تصور کرسکتی ہے جس سے وہ آشنائی رکھتی ہو۔ اوہام اور افہام میں وہی چیزآسکتی ہے جسے حواس درک کرسکیں اور حواس کی پہنچ میں ہوں اور مشاہدے ميں آسکیں ۔ حواس وہ کھڑکیاں ہیں جن کے ذریعے ابتدائی اور سطحی معلومات ذہن تک پہنچ سکتی ہیں ۔ امیرالمومنینؑ نے نہج البلاغہ میں متعدد مقامات پہ مشاہدہ پرستی کی نفی فرمائی اور مختلف تعبیرات کے ذریعے حواس کی محدودیت کی طرف اشارہ فرمایا ہے جیسے”لا تَقَعُ الْأَوْهَامُ لَهُ عَلَى صِفَةٍ” "لَايُدرِكُ بِالحَوَاسِ” ،” لَا تُدرِکُهُ الشَّوَاهِد” ، "لَا تُدرِکُہُ العُیُونُ” ،”وَ لُا تُحِیطُ بِه الَابصَارُ”، "وَ لا تُعْقَدُ الْقُلُوبُ مِنْهُ عَلَى كَيْفِيَّةٍ” یعنی اسے حواس (senses) کے ذریعے درک(apperception) نہیں کیا جاسکتا ہے نہ ہی احاطہ کیا جاسکتا ہے۔
عقل کی محدودیت کی حد یہ ہےکہ مخلوقات میں سے کئی ایسی چیزوں کی تصویر ذہن میں نہیں لا سکتی ہےجسے کبھی اس نے دیکھی نہ ہوجیسے کہ کائنات کے خارج میں کیا ہے، مادے کے چوتھے بُعد (fourth dimension) کی تصویر کس طرح کی ہوگی۔ آج تک کسی سائنسدان نے یا کسی انیمیشن بنانے والے نے چار بُعدی (four dimensional) تصویر نہیں بنائی ہے اور نہ ہی بناسکے گا۔ "كَيْفَ يَصِفُ إِلَهَهُ مَنْ يَعْجِزُ عَنْ صِفَةِ مَخْلُوقٍ مِثْلِه” پس وہ انسان جو اپنی جیسی مخلوق کی صفت بیان نہیں کرسکتا ہے اسے خالق لم یزل کا تصور و توصیف کیسے ممکن ہے۔
ہمارے لیے مُیسر اُس کے اوصاف (divine attributes)اس کی حقیت ِ اعلی و کُنْہِ ذات (very nature)کو کشف نہیں کرسکتے ہیں "انحسرت الاوصافُ عن كُنْهِ معرفته” ،کیونکہ صفات فقط اس شے کو کشف کرسکتی ہیں کہ جس کی کوئی ہیئت(form)، کمیت (quantity) ، کیفیت (quality) یا اعضا و جوارح ہوں "وَ إنَّمَا يُدْرَكُ بِالصِّفَاتِ ذَوُو الْهَيْئَاتِ وَ الْأَدَوَاتِ"، نہ ہی عقول اسے درک کرسکتی ہیں کیونکہ اس مقام پر جہاں اس کی کنہِ صفات (core of quality)عقول تک پہنچی ہی نہیں ہے وہاں عقول کے دریچے ذات کے عدم ِادراک کی وجہ سے الجھ کرپلٹ جاتے ہیں، نہ ہی دل کی آواز اس کی کُنہِ صفت تک پہنچ سکتی ہے کیونکہ دلِ حزین کے ہَماہِم اور زمزے(humming) اس کی صفت کے کنہ کے ادراک سےمایوس ہوکر پھرجاتے ہیں "رَدَعَ خَطَرَاتِ هَمَاهِمِ النُّفُوسِ عَنْ عِرْفَانِ كُنْهِ صِفَتِه"۔ کیونکہ اس کی نہ حد ہے، نہ ہیئت ہے، نہ مقام ہے، نہ مکان ہے، نہ زمان کے تغیرات اس پہ جاری ہوسکتے ہیں، اس کی ذاتِ احدیت لا متناہی (infinite)ہے کہ جسے کسی خاص حد مثلا کمیتی، کیفتی یا ماہیتی حدود میں مقید نہیں کیا جاسکتا۔ اس کی ذات، عظمت اور صفات کی انتہا کو انبیا بھی نہ پہنچ سکے نہ ہی اولیا پہنچے،تبھی تو اس کی ذات کےبارے میں سوچنے سے بھی منع فرمایا کیوں کہ اس کی ذات کے بارے میں سوچیں توسوائے حیرت اور سرگردانی کے اور کوئی نتیجہ نہیں ملے گا مزید فرمایاکہ اس کی ذات کے بارے مت سوچو کہ تم زندیق بنوگے۔وہ عقول پر جلوہ گر ہی نہیں ہواہے کہ عقول اس کی حد بندی کرسکیں "لَمْ يُطْلِعِ الْعُقُولَ عَلَى تَحْدِيدِ صِفَتِهِ وَ لَمْ يَحْجُبْهَا عَنْ وَاجِبِ مَعْرِفَتِه” لیکن کچھ واجبی معرفت ناممکن بھی نہیں ہے۔
ممکنہ معرفت
عقول اس کی حدبندی نہیں کرسکتی ہیں لیکن کچھ واجبی سی معرفت انسان کے لیے ممکن ہے کہ اس سے وہ چھپا نہیں ہے۔البتہ ابن سینا ؒ کی نظر میں ہر کس و ناکس کا ذہن اس کا ادراک نہیں کرسکتا ہے وہ خاص بندے ہیں کہ جو ممکنہ معرفت تک رسائی حاصل کرسکتے ہیں( جیسے ہرسٹوڈینٹ یونیورسٹی جاتا ہے لیکن آئن سٹائن جیسا سائنسدان نہیں بن سکتا ہے یعنی وہ دماغ نہیں ہے کہ قدرتی حقائق سمجھ سکے اور دریافت کرسکے) ، یہ وہ دریا ہے جہاں انسان غرقاب ہوجاتا ہے ، اس سمندر میں اترنے سے پہلے لازمی تیاری بہت اہم ہے اور اس میدان کا ذہن ہونا ضروری ہےوگرنہ خیالات کے سمندر کی طغیانی میں انسان غرقاب ہوجائے۔جناب بوعلی سیناؒ نصیحت کرتے ہیں کہ اس سمندر کے تیراک کو ماہر ، تیز، ہوشیار، نفس کی پاکیزگی، استقامت اور حقیقت کے سامنے تسلیم ہونے والی روح چاہیے ، ان الہیاتی مسائل میں غوطہ زنی کے لیے بہت ہی برجستہ اور یگانۂِ روزگار عقول کی ضرورت ہے، ہر کس و ناکس اس شرط پہ پورا نہیں اترتا ہے، شہید مطہری کے بقول ابن سیناؒ کی یہ نصیحت حدیث نبوی کی طرف اشارہ ہے کہ "ہر کسی را بہر ِ کاری ساختن” یعنی ہر شخص کو ایک خاص کام کے لیے بنایا گیاہے وہ اسی کا ماہر ہوسکتا ہے۔ ابن سیناؒ الہیات کے ماہرین کو نصیحت کرتے ہیں کہ اس میدان میں اترنے والے شاگرد کو تدریجا اور قدم بہ قدم الہیاتی مسائل سکھائیں، پہلے والے درس کا امتحان لیں ، اگر صحیح سمجھ چکا ہے تو آگے بڑھیں اور جس دن پیچیدہ مسائل سکھانے ہوں اس دن ایسے ہی نہ سکھائیں بلکہ دیکھیں کہ آج شاگرد ذہنی طور پر تیار ہے یا نہیں ہے ، اگر ذہنی طور پر تیار نہیں ہے تو ا س دن نہ سکھائیں۔ شاگرد سے عہد لیں اور قسم کھلائیں اور تاکید کریں کہ یہ دقیق عقلی مسائل عام عوام کو نہ سکھائیں کیوں کہ وہ اس کے اہل نہیں ہیں۔
ممکنہ شناخت میں آراء
یہ بیان ہوا کہ کنہ معرفتِ الہی کی حقیقت کسی کے توان میں نہیں ہے لیکن جو ممکنہ شناخت تک بشر کا ذہن اور قلب پہنچ سکتا ہے اس کے بارے میں مسلمانوں کے ہاں مختلف آرا سامنے آئی ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ انسانی عقل اللہ کی صفات کو پہچان ہی نہیں سکتی ہے عقل کے لیے کوئی راستا نہیں ہے کہ اللہ کی صفات کو پہچانے۔ ان کا خیال ہے کہ ہم اجمالی طور پر اللہ کی صفات جو قرآن اور حدیث میں آئی ہیں ان پہ ایمان لائیں لیکن ان سے آگاہی جو کہ ناممکن ہے اسے ایسے ہی رہنے دیں۔ اس گروہ کو جو انسانی عقل کے عدمِ ادراک کے قائل ہیں انھیں "مُعَطّلہ” کہا جاتا ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ کیوں کہ خدا وند تعالی واجب الوجود (Necessary being)ہے جب کہ ہم مخلوق ہیں، خدا کے اوصاف جو قرآن اور حدیث میں آئے ہیں یہ حقیقت میں انسانی صفات ہیں انھيں خدا کی طرف نسبت نہيں دیا جاسکتا ہے کیوں کہ خدا کسی بھی مخلوق کی طرح نہیں ہے اس و جہ سے ہم ان انسانی صفات کو اس کی طرف نسبت نہیں دے سکتے ہیں ، ہمارے پاس جو بھی صفات ہیں وہ ممکن الوجود (Contingent being)کی صفات ہیں ان کے علاوہ کوئی صفت ہمارے پاس نہیں ہے۔پس چارہ نہیں ہے کہ ہم اوصافِ الہی کے بارے میں سکوت اختیار کریں اور اجمالی طور پر تصدیق کریں۔ یہ گروہ تنزیہِ خداوندی (transcendence) میں افراط کی طرف گئے اور عقل کو سرے سے ناتوان خیال کرنے لگے کہ ہماری عقل ممکنہ صفات بھی درک نہیں کرسکتی ہے، ان میں سے بعض اس حد تک تنزیہ کی طرف نہیں گئے لیکن کہتے ہیں کہ ہم خدا کے اوصاف کو تو درک نہیں کرسکتے ہیں کیوں کہ اس سے تشبیہ لازم آتی ہے لیکن ہم کوئی ثبوتی صفت ثابت کرنا چاہیں تو لازما وہ انسانی صفت ہوگی اور اس سے تشبیہ لازم آئے گی، پس چارۂ کار یہ ہے کہ ہم ان صفات کو خداوند تعالی کی ذات سے نفی کریں، جیسے جب ہم کہنا چاہیں کہ خد اعلیم، قدیر اور حی ہے تو اس سے یہ سمجھیں کہ وہ جاہل، عاجز اورمیت نہیں ہے۔
ان کے مقابلے میں اکثر مسلمان متکلمین (dialectical theologian) اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ اللہ کی ممکنہ صفات کو عقلِ انسانی درک کرسکتی ہے اور اس کی صفات (attributes) کے ذریعے ممکنہ شناخت حاصل کی جاسکتی ہے۔ البتہ یہ بھی دو گروہوں میں منقسم ہیں ، ان میں سے پہلا گروہ جس کا خیال ہےکہ اللہ کےاوصاف جن کے ذریعے ہم اللہ کی معرفت حاصل کرسکتے ہیں ان میں اور انسانی اوصاف ميں کوئی فرق نہیں ،یہ اوصاف انسان اور خدا دونوں کے لیے یکساں معنی رکھتے ہیں۔ اس گروہ کو جو اوصاف الہی کو انسانی صفات سے مشابہ مانتے ہیں اورکسی فرق کے قائل نہیں "مُشَبّہہ” (anthropomorphist)کہتے ہیں، ان میں سے بعض تو اللہ کے جسم ، ہاتھ اور پاؤں کے قائل ہیں یہ اپنی تائید کے لیے بعض قرآنی آياتِ متشابہات (multivalent verses)سے دلیل لاتے ہیں، جب کہ ان آیات کی تاویل کا حکم دیا گیا ہے۔
دوسرا گروہ انسانی اور الہی صفا ت میں فرق کے قائل ہے اگرچہ لفظی طور پر مشترک (heteronym)ہیں لیکن معانی بالکل مختلف ہیں ، ہم تنزیہ اور تشبیہ کے درمیان رہ کر ایک الگ معنی لے سکتے ہیں اور ہم ایک معقول و محدود حد تک اسے پہچان سکتے ہیں ہرچند ہم کنہ ذات (very nature) اور کنہ صفات (core of attributes)تک نہیں پہنچ سکتے لیکن امکانی حد تک توصیف ممکن ہے اگرچہ عقول اسے صفات ميں محدود نہیں کرسکتے یہ ائمہ اہلبیت علیہم السلام کے مکتب کے لوگ ہیں کہ انھوں نے خود ائمہ اہلبیتؑ کی رہنمائی میں ہی یہ عقلی نظام ترتیب دیا۔
صفات سلبیہ
ایسی صفت جو ذاتِ واجب اور مستقل کے لیے محال اور ممتنع ہو اس صفت کو صفتِ سلبی(negative attribute) کہا جاتا ہے اس کا یہ معنی نہیں کہ اُس سے کمال اور وجودِ مستقل کی صفات کی نفی کی جائے، البتہ صدر المتالہینؒ نے صفات جلالیہ کہنا زیادہ مناسب سمجھا ہے ۔ صفاتِ سلبیہ تمام بڑے ادیان میں خدا وند کی ذات کےلیے شمار کیا گیاہے، انھیں سب سے پہلے ہندو مذہب میں اللہ (براہما) کی صفات کے طور پرشمار کیے ہیں اور بطورِ صفات بہت تاکید کی گئی ہے، ویدوں(Vedas) میں خدا کو یوں یاد کیا ہے لا صدا، لا محسوس، لا صورت، لا زوال،لا طعم، لا شمَّہ، لا زمان ، لامکان۔ اسی طرح مسیحیت، یہودیت، بدھ مت اور اسلام میں صفاتِ سلبیہ کو اللہ کی صفات کے طور پر شمار کیا گیا ہے۔ صفات ثبوتی سے بھی بڑھ کر خداوند سبحان کو ممکن الوجود اور حادث کی صفات سے منزہ کر نے کے لیے صفاتِ سلبیہ سے بڑھ کر کوئی اور صفات نہیں ہیں۔ حی، عالم اور قدرت مند ہونا انسانی صفات بھی ہیں، ذاتِ واجب جب تک صفات سلبیہ سے منزہ نہ کیا جائے تب تک ایک ممکن الوجود اور غیر مستقل وجود کے علاوہ کچھ ثابت نہیں ہوتا ہے ، اس وجہ سے کئی لوگ ہیں جو علت اولی کو تو مانتے ہیں لیکن مصداق میں اشتباہ کر تے ہوئے انرجی، ایٹم یا کوانٹم زرات کو ذات واجب اور مستقل سمجھتے ہیں۔
لہذا لازمی ہے کہ وجودِ مستقل(being himself) کی تنزیہی صفات کو بیان کیا جائے تاکہ وجودِ مستقل، وجودِ غیر مستقل(existence by something) سے جدا ہوجائے۔ جب واجب الوجود کی صفت بیان کی جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ ساری مادی کائنات وجودِ مستقل بننے کی صلاحيت نہیں رکھتی۔ مادہ ،ایٹمی ذرات اور نیچرل قوانین خد اکے جائیگزین نہیں بن سکتے ،کیوں کہ وہ آفل اور زائل ہیں، پس کوئی آفل اور زائل جو خود محتاج ہو وہ کیونکر میرا خدا ہوسکتا ہے۔
مکتبِ اہلبیتؑ کے کئی متکلمین کی نظر میں اللہ کی سلبی صفات سات ہیں جب کہ محقق علما کے ہاں تعداد معنی نہیں رکھتی ہے ۔ درست بات یہ ہے کہ ہر وہ صفت جو ممکن الوجودکی صفت ہو وہ ذات واجب کی صفت نہيں بن سکتی ہے، سلبی صفات سے متصف موجود مخلوق تو ہو سکتا ہے واجب الوجود اور علتِ اولی(first cause)نہیں ہوسکتا ہے، وہ ایک محتاج اور فقیر ہستی تو ہوسکتی ہے واجب الووجود نہیں ہوسکتی ہے۔ ہم ذاتِ واجب کی سلبی صفات میں سے فقط ایک صفت "لامکانی” کا جائزہ لیں گے۔
مکان
لغوی معنی:”مکان” (place)لفظ "ک و ن” سے ماخوذ ہے اوراسمِ مکان کے وزن”مفعل” پہ ہونے کی وجہ سے "مکان” بن گیا جس کا معنی ہے جگہ ۔ کلام، فلسفہ، منطق،تصوف، سائنس اور کئی دوسرے علوم نے مکان کےبارے میں بحث اور مختلف تعریفیں بیان کیے ہیں۔ فلسفیانہ نظر سے ارسطو، افلاطون، ڈیکارٹ، ابن سیناؒ، علامہ نصیرالدین طوسیؒ ، ملا صدراؒ، کانٹ ، لیبنز، نیوٹن ، آئن سٹائن ، علامہ اقبالؒ، علامہ طباطبائیؒ اور علامہ مصباح یزدیؒ غرضیکہ ہر فلسفی نے اس بحث کو چھیڑا ہے۔ مکان و زمان فلسفہ یا سائنس کے پیچیدہ ابحاث میں سے ہے اس وجہ سے فلاسفہ کے درمیان معرکۃ الآرا ءابحاث میں شامل رہا ہے اور مکان کو "خدا” سے لے کر "وہم” تک کہا گیا ہے۔ فلسفہ میں مکان کی مختلف تعریفیں بیان ہوئی ہیں لیکن ان ميں سے جو ہمیں بہتر لگی وہ آيت الله مصباح یزدیؒ کی ہے کہ ؛ جب بھی کائنات کے حجم کی ایک خاص مقدار کو الگ سے لحاظ کیا جائے اور اسے اس میں سمائے ہوئےشے کے ساتھ جانچا جائے تو یہ مقدار مکان کہلائے گا۔
مکان ایک عرَضی (accidental) اور اضافی(relative) مفاہیم میں سے ہے اس سے مراد یہ ہے کہ بعض مفاہیم کو سمجھنے کے لیے اسے دوسری شے کے ساتھ لحاظ کرنا ضروری ہوتاہےجیسے حرکت ہے، آپ حرکت کو تنہا سمجھ نہیں سکتے جب تک متحرِک شے کو ایک دوسری شے (reference) سے لحاظ نہ کریں جیسے چلتی ہوئی گاڑی کو آپ اپنے آپ سے لحاظ کرکے کہتے ہیں کہ گاڑی چل رہی ہے۔ مکان کی چار خصوصیات ملا صدرا نے شمار کی ہیں کہ جسم منتقل یا ساکن ہوسکے، اشارہ کیا جاسکے، مقدار رکھے اور ہم زمان دواجسام نہ سموسکیں۔ فضا اور مکان میں بھی فرق ہے، مکان تب کہلائے گا جب مکان کومکان دار سے لحاظ کیا جائے جبکہ فضا کے لیے دوسری شے مدنظر نہیں ہوتی ہے۔ مکان متغیر بھی ہوسکتا ہے جیسے پانی میں مچھلی ہے پانی بار بار بدل رہا ہے ہر لمحہ نیاپانی آرہا ہےپہلا پانی گزر رہا ہےاسے کہا جائے گا کہ مکان بدل رہا ۔
بشکریہ: risalaat.com